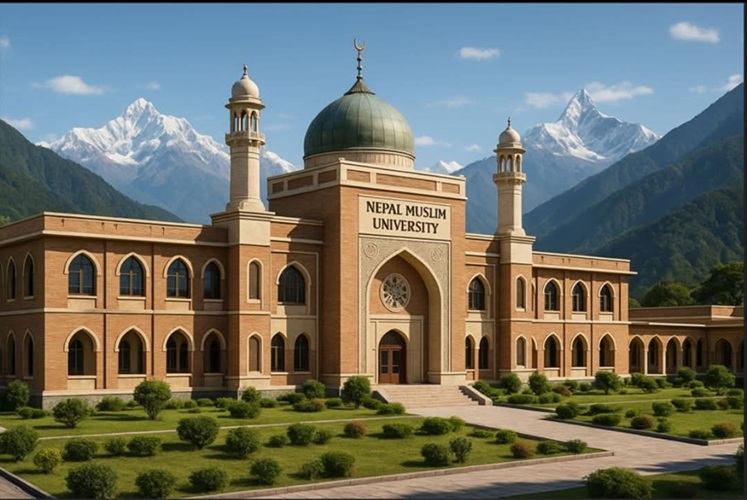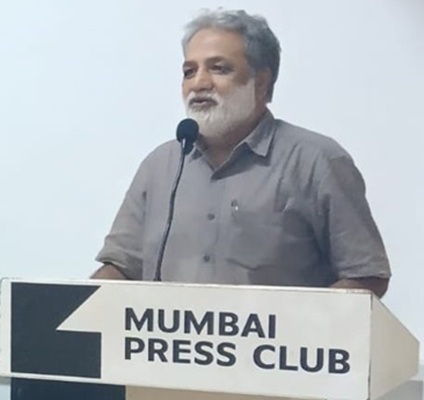انسانی زندگی میں وسائل معیشت، نظم معیشت اور کسب معاش کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اس کے پیش نظر تاریخ انسانی کے ہر دور میں اس مسئلہ کے حل کے لیے ہمہ نوع اور باہم لوگ متضاد نظریات پیش کیے جاتے رہے، جو زمان ومکان کے ساتھ ساتھ بدلتے مٹتے اور تبدیل ہوتے رہے۔
دور جدید میں جب علوم کی نوعی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا تو معاشیات کو ایک الگ علم اور سائنس کی حیثیت حاصل ہوئی، علم معاشیات کی تدوین کے موقع پر ماہرین معاشیات نے جب اس کے اصول و قواعد مرتب کئے تو پیداواری عمل کے لیے زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کو یکجا کرنا لازمی اور ضروری قرار دیا اور اصول وضع کردیا کہ ان عوامل پیداوار کے مجتمع اور منضبط ہونے کی صورت میں کسی پیداواری عمل کا نتیجہ خیز ہونا ممکن سمجھا جاسکتا ہے۔
اسلام نوع انسانی کے لیے عالم گیر، دائمی، حتمی اور کامیابی کا ضامن لائحہ عمل مہیا کرتا ہے اور اپنی وسعت ہمہ گیری اور اکملیت کے باوصف اس نے حیات انسانی کے تمام پہلوؤں کیلئے جو جامع و مانع پروگرام مرحمت فرمایا ہے اس میں معاشی زندگی کے مسائل اور ان کے حل کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
معاشی جد و جہد اور کسبِ معاش کے لیے اسلام کے فراہم کردہ اصولوں میں محنت، اور اس کی ضرورت و عظمت، سرمایہ اس کا حصول و صرف، زمین اس کی ملکیت، پیداواری صالحیت اور اس پر محنت کے اصول، مارکٹنگ اور معاشی لین دین میں صداقت و امانت دیانتداری و راست بازی، حق گوئی و سچائی کی اہمیت اور دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، بلیک مارکٹنگ اور ملاوٹ کی مذمت، رشوت اور سود کی حرمت اور مخرب اخلاق ذرائع آمدنی کی حرمت شامل ہے جبکہ معاشرتی زندگی کے حوالہ سے، ہمدردی، غم گساری، ایثار و قربانی اور انفاق فی سبیل اﷲ کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ مختصرا کسب معاش کے یہ سنہری اصول جس نقطہ کے گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ہے عدالت و امانت اور حق گوئی و راست بازی۔
محنت:
کسب معاش کے حوالہ سے کسی بھی جد و جہد کا آغاز کیا جائے، محنت کو اس میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہوگی۔ اسلام محنت و کوشش اور اس کے ذریعہ حاصل شدہ دولت کو خاص قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چند نظائر ملاحظہ ہوں:
١- ما اکل احد طعاماً قط خیراً من ان یاکل من عمل یدہ و ان نبی اﷲ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ۔
”یعنی کوئی شخص اپنی ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی چیز نہیں کھاتا، اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔
ب- لان یحتطب احدکم حزمۃ علی ظہرہ خیر من ان یسال الناس احد فیعطیہ او یمنعہ۔”
‘تم میں سے کوئی اپنی پشت پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی سوال کرے کوئی اسے دے یا نہ دے۔
معاشی جد و جہد کے حوالہ سے آپؐ صلی اﷲ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نگاہ ڈالیں توکئی ایک تجارتی اسفار جن میں شام بصرہ اور یمن کے تجارتی سفر قابل ذکر ہیں۔ قبل از نبوت زندگی میں ملتے ہیں۔ اسی طرح عرب کے مختلف بازاروں میں آنحضور صلی اﷲ علیہ وسلم کی معاشی مصروفیات کا ذکر ابن سید الناس نے کیا ہے۔ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اﷲ علیہ اجمعین نے بھر پور معاشی جد وجہد فرمائی اور اپنی اس پاک کمائی سے اﷲ کی راہ میں صدقہ بھی فرمایا کرتے۔
سرمایہ اور حصولِ سرمایہ:
معاشی جد و جہد اور کسبِ معاش کا کوئی بھی عمل دولت کے بغیر شروع کرنا اور اسے جاری رکھناممکن نہیں بطور خاص دورِ حاضر کے معاشی حالات میں اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام دولت کو ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ اسے خیر کے لفظ سے تعبیر فرماتا ہے۔
ا- وانہ، لحب الخیر لشدید۔
”بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔
ب- وما تنفقوا من خیر یوف الیکم۔
”اور تم مال میں سے جو کچھ خرچ کروگے تمہیں پورا ادا کردیا جائے گا۔
ج- وما تنفقوا من خیر فان اﷲ بہ علیم۔
”اور اپنے مال میں سے جو کچھ تم خرچ کروگے اﷲخوب جاننے والا ہے۔
مگر مال کے حصول میں دیانت و امانت کے اصول کو مرکزی نکتہ کی حیثیت دی گئی ہے۔ تاکہ باہمی مفادات کا احترام و تقدص قائم رہ سکے۔ فرمایا:
ا-یا یہا الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔
”اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقہ سے مت کھاؤ۔”
ب- واتو الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب۔
”اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ردی چیز کو عمدہ چیز سے تبدیل نہ کرو۔
ج- ان الذی یاکلون اموال الیتامیٰ ظلماً انما یاکلون فی بطونہم نارا۔
”بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے شکموں میں دوزخ کی آگ کھا رہے ہڈں۔
حضور اکرم صلی اﷲ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اﷲ لہ النار وحرم علیہ الجنۃ فقال رجل وان کان شیأا یسراً یا رسول اﷲ قال وان قضیاً من۔
جس نے مسلمان کا حق قسم کے ذریعہ ختم کردیا اسے ضرور دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس پر جنت حرام ہوگی۔عرض کیا گیا کہ اگر بہت معمولی سی چیز کا معاملہ ہو تو (پھر بھی ایسا ہی ہوگا) فرمایا اگرچہ اراک کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔
من اقتطع شبراً من الارض ظلماً طوقہ اﷲ ایاہ یوم القیامۃ من سبع ارضین۔
”جس شخص نے ظالمانہ طور پر کسی سے زمین کا کچھ حصہ لے لیا، قیامت کے روز اﷲ تعالیٰ اسے سات زمینوں کا بوجھ اس کے گلے میں ڈال دے گا۔
من ظلم من الارض طوقہ من سبع ارضین۔
”جو کسی کی بالشت برابر بھی زمین ہتھیالے گا اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔
حلال و حرام کی تمیز:
پیدائش دولت کے عمل میں ظلم و استبداد کی ظاہری صورتوں کے علاوہ خفیہ اور غیر محسوس طریقوں سے بھی عوام الناس کو ان کے جائز مال سے محروم کیا جاسکتا ہے اسی وجہ سے اکتسابِ رزق کے عمل کو حلال و حرام دو واضح اصطلاحات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جائز ذرائع مثلاً تجارت اور محنت وغیرہ سے حاصل کردہ دولت حلال اور اس کے برعکس تمام صورتیں ممنوع اور حرام ہیں۔ ان صورتوں میں سے ایک کے بارے میں بطور مثال قرآن فرماتا ہے:
واحل اﷲ البیع وحرم الربو۔
”اﷲ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا ہے۔”
تجارت تمام جائز وسائل دولت اور ذرائع معاش کو بیان کرتی ہے جبکہ سود ظلم و واستحصال کی تمام صورتوں کی نشاندہی کرتا ہے کاروبار تجارت اور کسبِ معاش کا عمل ہر چند کہ انتہائی پاکیزہ ہے اور آپ ؐ صلی اﷲ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہدائ۔
”سچے اور امانتدار تاجر کا حشر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔”
آپ ؐصلی اﷲ علیہ وسلم نے کسب معاش کی ایسی تمام صورتوں کو حرام قرار دیا ہے جوغیر عادلانہ بنیادوں پر استوار ہوتی ہوں ناجائز منافع خوری کے حوالہ سے فرمایا:
من احتکر فہو خاطی
”جو شخص گرانی اور مہنگائی کی غرض سے غلہ (اور دیگر اشیاء صرف) روکتا ہے وہ گنہ گار ہے۔
بلکہ اﷲ کی نگاہ میں ذخیرہ اندوزی کرنے والا بدترین شخص ہے۔
کسب معاش میں ایسے ظالمانہ طرز عمل کے اختیار کرنے والے کا کوئی نیک عمل بھی اﷲ کے یہاں شرف باریابی نہیں پاتا۔ آپؐ نے فرمایا:
دورِ حاضر میں اہل ثروت و دولت اور سرمایہ دار بسا اوقات کسی جنس کو مکمل طور پر مارکیٹ سے خرید کر لیتے ہیں اور بعد ازاں اپنی مرضی سے ان کی رسد طلب میں عدم توازن قائم کرکے من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ ایسی تمام صورتیں اسلام کی نظر میں مطلقاً حرام ہیں۔
سود:
دنیا کے قدیم و جدید معاشروں میں سود کی شکل میں معاشی استحصال صاحب ثروت کی طرف سے درست سمجھا جاتا ہے۔ دور جدید کی معاشیات نے پورے معاشی ڈھانچے اور کاروباری لین دین کو کچھ اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ ”سود” بین الاقوامی سطح کے معاملات میں جز و لاینفک کی حیثیت اختیار کرچکا ہے۔ معاشی تعلقات کا کوئی پہلو، انفرادی اجتماعی اور بین الاقوامی سطح پر ایسا نظر نہیں آتا جہاں یہ ”لعنت” کینسر کے پھوڑے کی طرح اپنی جڑیں نہ پھیلا چکی ہو۔ مگر اسلامی معیشت اور کسب معاش کی اسلامی اقدار میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اپنی کاروباری زندگی کو سہارا دینے کے لیے سودی لین دین کو جائز سمجھ لے، اﷲ تعالیٰ جیسی مہربان ذات چونکہ استحصال کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں فرماتی لہٰذا معاشی استحصال کو سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے فرمایا:
واحل اﷲ البیع وحرم الربو۔
”اﷲ نے خرید و فروخت کوحلال اور سود کوحرام قرار دیا ہے۔”
یا الذین امنوا القو اﷲ وذروا مابقی من الربو۔
”اے ایمان والو اﷲ سے ڈرو اور سود کی باقی (تمام رقم) چھوڑ دو۔”
فإن لم تفعلوا فاذنوا بحربٍ من اﷲ ورسولہ۔
”اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اﷲ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔”
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم کے بالکل قریب زمانہ میں قیصر روم نے، جس کی وفات آپ ؐ کی پیدائش سے صرف پانچ سال قبل ہوئی تھی۔ تمام بازنطینی سلطنت میں ازروئے قانون زمینداروں اور کاشت کاروں کے قرضوں پر ٤% فیصد، تجارتی اور صنعتی قرضوں پر ٨%، اور بحری تجارت کے قرضوں پر ١٢% شرح سود مقرر کی تھی۔
(سود از مولانا مودودی ص ٢٨٧ بحوالہ (١) رول ڈورانٹ (ج ٤ ص ١٢٠، ٤٣٦ Civilisation Astory of ) زوال وسقوط دولت روم ازگین ج ٢ ص ٧١٦)
تجارتی سود اور قرآن کریم:
اسلام نے تجارتی اور شخصی قرضوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ضرور اس کی وضاحت کردی جاتی۔ قرآن کی نگاہ میں اصل سے جو کچھ بھی زائد لیا جائے اور جس طرح بھی لیا جائے، خواہ وہ مقرہ شرح سے ہو یا بالمقطع ہو، وہ ”ربا” ہی ہے۔ ربا کے لغوی معنی بھی وہ مخصوص اضافہ ہے جو اصل سے زائد لیا جاتا ہے۔
اﷲ تعالیٰ فرماتے ہیں:
واحل اﷲ البیع وحرم الربوا۔ (٢/٢٧٥)
”اﷲ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔”
یہاں خرید و فروخت یا تجارت کے مقابلے لفظ ربا کا استعمال تجارتی سود کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیونکہ جہاں حاجات کے قرضوں کا ذکر مقصود تھا وہاں قرآن کریم نے ربا کے مقابلے صدقہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے:
یمحق اﷲ الربو ویربی الصدقات۔ (٢/ ٢٧٦)
”اﷲ تعالیٰ سود کو ختم کرتا اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔
ارشاد باری ہے:
وان تبتم فلکم رء وس اموالکم۔ (٢/٢٧٩)
” اور اگر تم توبہ کرلو تو تمہارے لیے تمہارے راس المال ہیں۔
اس آیت میں تجارتی قرضوں کے سود کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے۔ کیونکہ لفظ راس المال (سرمایہ) کا اطلاق کاروبار پر لگائی ہوئی رقم کے لیے ہوتا ہے۔
سود کی حرمت کی علت ظلم نہیں بلکہ بیٹھے بٹھائے اپنے مال میں اضافہ کی ہوس ہے سود کے متعلق سب سے پہلی آیت جو مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔
ارشاد باری ہے:
وما اٰتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند اﷲ۔ (٣/٢٩)
”اور جو رقم تم سود پر دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے اموال سے بڑھتی رہے تو یہ مال اﷲ کے ہاں نہیں بڑھتا۔
بفرض محال ہم یہ تسلیم کرلیں کہ حرمت سود کی علت ظلم ہی ہے اور یہ بھی کہ چونکہ سودی معاہدہ باہمی رضامندی سے طے پاتا ہے اور یہ بھی فریقین میں سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ لیکن اصل مظلوم تو وہ معاشرہ ہے جس پر ان دو حرام خوروں کے اس سودی کاروبار کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
ربا میں نفع و نقصان کا تقابل:
ایسے شرعی احکام میں، جو نص قطعی سے ثابت ہوں، نفع و نقصان کا تقابل کرنا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں، کیونکہ انسانی عقل کسی چیز کے نفع و نقصان کا مکمل احاطہ نہیں کرسکتی۔ شراب اور جوئے کے متعلق قرآن کریم میں جو نفع و نقصان کا تقابل کیا گیا ہے۔ وہ خود اﷲ تعالیٰ نے کیا ہے جو خود فریق نہیں بلکہ اس کی نظر سب نوع انسانی پر ایک جیسی ہے۔ اﷲ نے اسے شرابیوں اور جواریوں کے فیصلے پر نہیں چھوڑا اگر ایسی بات ہو تو وہ یقینا شراب اور جوئے کے فوائد ہی زیادہ بتلائیںگے۔ پھر سود کے حامیوں کو اس تقابلی کا حق کیونکر دیا جاسکتا ہے؟
سود کی اقسام اور مختلف شکلیں
سود کی بالکل سادہ اور معروف شکل یہ ہے۔ کہ مثلا زید، بکر سے ایک سو روپے ایک سال کیلئے قرض لیتا ہے اور پندرہ فیصد شرح سود طے ہوتی ہے۔ تو زیدایک سال گزرنے پر ایک سو روپے اصل رقم جمع پندرہ روپے کو اصل زر شمار کرکے اسے مزید مہلت دے دے گا۔ اسے عام زبان میں سود مرکب یا سود در سود کہتے ہیں۔ سود مفرد کی مدت ایک سال بھی ہوسکتی ہے، چھ ماہ بھی، تین ماہ بھی حتی کہ اگر ضرورت مند سخت مجبور ہے تو ایک ماہ بھی ہوسکتی ہے۔ اس طرح سود مرکب کی رقم سود مفرد سے بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ جس کے متعلق اﷲ تعالیٰ فرماتے ہیں:
یا یہا الذین امنوا لا تاکلوا اضعافا مضاعفۃ۔ (٣/١٣٠)
‘اے ایمان والو! بڑھو تری در بڑھو تری والا سود مت کھاؤ۔”
ربا النسیئہ:
سود کی یہ صورتیں بالعموم معروف اور مروج ہیں۔ ان تمام صورتوں میں زائد رقم چونکہ مدت یا مہلت کے عوض لی دی جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے سود کو شرعی اصطلاح میں ربا النسیئہ کہا جاتا ہے (یعنی مدت یا ادھار کی وجہ سے سود)
ربا الفضل:
مندرجہ بالا اقسام سود کے علاوہ سود کی ایک اور قسم بھی ہے جس سے صرف اسلام ہی نے متعارف کرایا ہے او روہ ہے ربا الفضل۔ ایسا سود جس میں مدت بھی نہ ہو اور جنس میں کمی بیشی بھی ہو۔ مثلاًزید کے پاس ناقص قسم کی گندم ہے اور بکرکے پاس اچھی قسم کی۔ زید بکر سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے چار کلو گندم لے لو۔ اور اس کے عوض اپنی گندم ٣ کلو دے دو۔ اور وہ دونوں آپس میں لین دین کرلیتے ہیں۔ ایسا لین دین نہ بظاہر سود معلوم ہوتا ہے او رنہ ہی دنیا اسے سود شمار کرتی ہے۔ لیکن اسلامی نقطہئ نظر سے بکر نے زیدسے جو زائد ایک سیر گندم لی ہے۔ تو یہ بھی اسی جنس میں بغیر مدت کے زیادتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی سود ہے اور ا اور ب دونوں سودی لین دین کے مجرم ہیں۔ اب ارشادات نبوی ملاحظہ فرمایئے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور (اعلی قسم کی کھجور) لے کر حاضر ہوئے تو آپؐ نے پوچھا یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے: ہمارے پاس ناقص قسم کی کھجور تھی تو میں نے اپنی دو صاع کھجور کے بدلے ایک صاع کا سودا کرلیا۔ تو آپ نے فرمایا:
اوہ! عین الربا عین الربا، لا تفعل ولکن اذا اردت ان تشتری فبع التمر ببیع اٰخر ثم اشتربہ۔ (بخاری کتاب الوکالۃ۔ باب اذا باع الوکیل شیأا نیز کتاب البیوع۔ باب بیع الخلط من التمر)
”اوہ! خالص سود، خالص سود۔ ایسا مت کرو، ہاں جب ایسا ارادہ ہو تو اپنی کھجور الگ بیچو اور پھر دوسرا سودا کرکے اپنے لیے خرید لو۔(٩٧ تا ٩٨)
ایک شبہ اور اس کا ازالہ:
اس حدیث سے بھی ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی جنس مثلاً ایک کلو گندم کا ایک ہی کلو گندم سے تبادلہ کرتا کون ہے؟ اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ کوئی ایسا تبادلہ کرے؟ تبادلہ یوں تو ہوسکتا ہے کہ ایک فریق مثلاً زید کی گندم بہتر ہے اور دوسرے فریق مثلاً بکر کی گندم ناقص ہے تو اس صورت میں میں بکر تو ضرور تبادلہ پر آمادہ ہوجائے گا مگر زید کو یہ بات کب گوارا ہوگی۔ الا یہ کہ وہ احسان سمجھ کر ایسا گوارا کرلے۔ اس ارشاد مبارک سے آپ کی مراد بھی یہی ہے کہ اگر ایک بھائی دوسرے کے لیے اتنا احسان کرسکتا ہے تو کرے ورنہ ایسا سوا دا نہ کیا جاـئے۔ گویا یہ حدیث کمی بیشی کے لین دین کی انتہائی ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ جس کے الفاظ اس ممانعت کی تاکید مزید کر رہے ہیں۔
سود کی رقم کو کہاں خرچ کیا جائے اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اسے غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کردیا جائے یا کبھی بینک سے قرض لینے پر جو سود عاید ہو اسکی ادائیگی اس سود سے کردی جائے۔ وغیرہ مگر یہ ساری مصلحتیں اس وقت دھری رہ جاتی ہیں جب ہم قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہیں:
یا ایہا الذین آمنوا انفقو من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ ٢/٢٦٧)
”اے ایمان والو! اپنی پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو اور ہم نے تمہارے لئے جو کچھ زمین سے نکالا ہے اس میں سے ناپاک چیز خرچ کرنے کا قصد مت کرو۔ ”
اور یہ ظاہر ہے کہ سود جیسی حرام اور ناپاک چیز پاک نہیں ہوسکتی۔
قرض حسنہ:
اسلام سودی کاروبار کی بجائے قرضِ حسنہ کا ادارہ قائم کرنے کا خواہاں ہے تاکہ ضرورتمندوں اور حاجتمندوں کی مناسب طور پر امداد کی جاسکے۔ اﷲ کریم نے قرض حسنہ کے لین دین کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرکے اس کی ضرورت و عظمت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا:
من ذالذی یقرض اﷲ قرضاً حسنا۔
”کون ہے جو اﷲ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔”
ملاوٹ:
کسبِ معاش کی جد و جہد کے دوران حصول دولت کی بعض آسان راہیں بھی نکل آتی ہیں جنہیں السام قطعاً جائز قرار نہیں دیتا مثلاً اشیاء صرف کی کوالٹی کو تبدیل کرکے گھٹیا شئے کو صحیح داموں میں بیچنا، مدینہ منورہ کی غلہ منڈی سے گزرتے ہوـے آپؐ نے ایک موقع پر فرمایا:
ما ہذا یا صاحب الطعام قال اصابتہ السماء یا رسول اﷲ قال افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس من غش فلیس منی۔
غلہ کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالنے کے بعد آپ صلی اﷲ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نچلی سطح پر گیلی گندم پڑی ہوئی ہے آپ صلی اﷲ علیہ وسلم نے اس تاجر سے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اﷲ بارش کی وجہ سے ایسا ہوگیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا گیلی گندم کو اس ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈالا گیا تاکہ لوگ اسے بہ آسانی دیکھ سکیں (یاد رکھئے) دھوکہ باز میرے دین پر نہیں ہوتا۔
المسلم اخوا لمسلم ولا یحل لمسلم باع من اخیہ بیعاً فیہ عیب الا بینہ۔
”آپؐ نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر بتائے کسی عیب دار چیز کو اپنے بھائی کے ہاتھ فروخت کردے۔”
گراں بازاری:
کاروباری زندگی میں بلا جواز قیمتوں کا بڑھانا بھی ایک پرکشش امر اور حصول دولت کا آسان ذریعہ ہے، رحمۃ للعلمین نے اس صورت حال پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:
عن ابی ہریرۃ نہی رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ ولسم ان یبیع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ ولا یخطب علیٰ خطبۃ اخیہ ولا تسال المرأۃ طلاق اختہا لتکفاء ما فی انائہا۔
”فرمایا شہر والا دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے اور دھوکہ دینے کی غرض سے قیمت مت بڑھاؤ اور کوئی (تاجر) اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے اور کوئی عورت اپنی ملسمان بہن کوطلاق نہ دلوائے کہ اس طرح اس کا لقمہ اپنے منہ میں ڈال سکے۔”
مخرب اخلاق معاشی ذرائع:
آسان و سہل ذرائع آمدنی میں رشوت کا شمار بھی ہوتا ہے جسے آنحضور صلی اﷲ علیہ ولسم نے ان الفاظ میں ممنوع فرمایا:
لعن رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ ولسم الراشی والمرتشی۔
”جوا، سٹہ، قمار بازی، شراب سازی، شراب فروشی، زنا اور محرک زنا امور اور دیگر مخرب اخلاق کام جن سے سوسائٹی کا اخلاقی معیار پست ہوتا ہو اسلام ایسے ذرائع کووسائل دولت اور کسب معاش کے طور پر اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔
ملاحظہ ہو:
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسٌ من عمل الشیطن فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔”
بے شک شراب، جوا او ربت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاسکو۔”
جابر بن عبد اﷲ رضی اﷲ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اﷲ علیہ سلمنے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا:
ان اﷲ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام فقیل یا رسول اﷲ ارأیت شحوم المیتۃ فانہا یطلی السفن ویدہن بہا الجلود ویستصبح بہا الناس فقال لاہو حرام ثم قال رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم عند ذلک قاتل اﷲ الیہود ان اﷲ لما حرم شحومہا جملوہ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ۔
”بے شک اﷲ اور اس کے رسول نے شراب، مردہ جانور، سور اور بتوں کو فروخت کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اﷲ مردہ جانور کی چربی کے بارے میں آپ کا ارشاد کیا ہے؟ جوکشتیوں میں لگائی جاتی ہے او رکھالیں اس سے چکنی کی جاتی ہیں اور لوگ اس سے چراغ بھی جلاتے ہیں۔ آپ صلی اﷲ علیہ وسلم نے فرمایا ”نہیں وہ بھی حرام ہے۔” پھر آپ نے اسی وقت فرمایا ”اﷲ” یہود کو غارت کرے۔ جب ان پر اﷲ کی طرف سے چربی حرام کردی گئی تو انہوں نے چربی کو پگھلاکر بیچ لیا اور اس کی قیمت کھا گئے۔”
یہاں اس امر پر توجہ دینا ضروری ہے کہ جوا یا سٹہ سے مراد صرف وہی جوا نہیں جونقد کے ذریعے کھیلا جاتا ہے بلکہ تجارتی کاروبار میں بھی یہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے، عہد جہالت میں تجارتی جوا کی چند شکلیں بیع ملامسہ، بیع منابذہ اور بیع مصادرہ وغیرہ رائج تھیں جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا تھا۔ جدید نظام معیشت میں بھی جوا کی یہ صورتیں لاٹری، ریس، سٹہ وغیرہ کے مہذب ناموں کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ جو اسلام کی نگاہ میں ممنوع ذرائع معاش میں شمار ہوتی ہیں۔
زنا کاری، بطور ذریعہئ معاش اپناـئے جانے کے بارے میں آپؐ فرماتے ہیں:
عن ابی مسعود الانصاری رضی اﷲ عنہ، ان رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ ولسم نہی عن ثمن الکلب وصرا البغی وحلوان الکاہن۔
”کہ آنحضور صلی اﷲ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زنا کی اجرت اور کہانت کا معاوضہ لینے سے منع فرمایا ہے۔”
حجۃ اﷲ البالغہ میں شاہ صاحب نے ان حکمتوں کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے بعض ذرائع معاش اور ان سے اکتساب کو حرام قرار دیا گیا ہے فرماتے ہیں۔
”شریعت میں جوا کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصلاً و حقیقتاً ایک شخص کو بلا وجہ اس کے مال سے محروم کردینے ہی کی ایک صورت ہے اور ہارنے والے شخص کا سکوت غصہ اور ناامیدی کے ساتھ ہوتا ہے جوا کھیلنے والا سہل پسندی کا عادی ہوجاتا ہے اور کسب معاش کے جائز ذرائع اختیار کرنے اور باہمی ہمدردی و ایثار، جو اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے، سے اعراض برتتا ہے، سود کی حرمت کی وجہ بھی یہ ہے کہ سودی کاروبار کے رائج ہوجانے کی صورت میں ہمدردی اور غمگساری اٹھ جاتی ہے اور اس کی جگہ بڑے بڑے جھگڑے اور نفرتیں جنم لیتی ہیں، شرا ب سازی اور شراب فروشی اور بتوں وغیرہ کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کا کاروبار جائز قرار دے دیا جائے تو اس سے وہ برائی روکنا ممکن نہیں جن کے پیدا ہونے کے احتمال کی وجہ سے انہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ شراب پینے کے لیے اور بت پرستش کے لیے بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ امور حرام ہیں تو ان کی بیع بھی حرام ہونی چاہئے۔
آپ صلی اﷲ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
ان اﷲ اذا حرم شیأاً حرم ثمنہ۔
”اﷲ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کی قیمت کو بھی حرام فرمایا ہے۔”
بخاری شریف کی مذکورہ حدیث میں زنا کی اجرت کوخبیث ناپاک اور حرام فرمایا گیا ہے اس ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”زنا” کی اجرت خبیث ہے اور آپؐ نے کاہن کواجرت دینے اور مغنیہ کے کسب سے جو منع فرمایا ہے اس کی دو حکمتیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ممنوعہ کسب معاش کے اختیار کرنے میں لوگوں کو معصیت کی طرف ترغیب ملتی ہے اور دوسرا یہ کہ ملاء اعلیٰ میں ایسے شخص کی حیثیت مبیع کے خصائل و اثرات کی حامل سمجھی جاتی ہے۔
قرآن و حدیث کے ان نظائر کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ فلم سازی، فلم فروشی، وی، سی، آر کے ذریعہ مخرب اخلاق لٹریچر کی ترویج و اشاعت سٹیج اور ٹی۔وی ڈرامے، کلب اور ٹھیٹر، مصوری اور غیر اخلاقی پنٹنگ اور دیگر مخرب اخلاق جن سے قوم اور مسلمان نسل کا اخلاق اور روحانی معیار وقار متاثر ہوتا ہو، اﷲ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسے معاشی ذرائع ناجائز ہیں۔
زمین:
کسب معاش کا ہمیشہ سے ایک باوقار، قدرتی ذریعہ رہی ہے۔ زمانہئ قدیم میں عام طور پر زمین کو پیداواری کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ صنعتی ترقی کے بعد جب سے زمین بنیادی عوامل پیداوار میں شامل ہوئی ہے۔ اس کی اہمیت و حیثیت میں تنوع آچکا ہے۔ زرعی پیداوار حاصل کرنے کے علاوہ زمین تمام صنعتی یونٹوں، کارخانوں، فیکٹریوں، تنظیمی اداروں اور دفاتر کے قیام میں بنیادی کردار ادا رکرتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کے بغیر دور جدید کی ترقی۔ عملا نا ممکن ہوکر رہ جاتی ہے۔
زمین کے حوالے سے اسلام کی بنیادی تعلیم اور فکریہ ہے کہ یہ ہے کہ اﷲ کریم کی ملکیت ہے۔
للّہ ما فی السموات وما فی الارض۔
”اﷲ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اﷲ کافی کارساز ہے۔
وﷲ ملک السموات والارض وما بینہما یخلق مایشائ۔
”اﷲ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان کے درمیانی ہے۔ وہ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔
رب العالمین نے اپنی مخلوق کی ضروریات کی تکفیل و تکمیل کے لیے جو نظام مرتب فرمایا ہے وہ زمین اس میں ایک اہم اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور تقریبا تمام قسم کی غذائی ضروریات کی فراہمی کا آغاز کسی نہ کسی صورت میں زمین ہی سے ہوتا ہے۔ اﷲ کریم نے اپنی مخلوق کے استفادہ کے لیے اپنی ”ملکیت زمین” کو مخلوق کی ”عارضی ملکیت” میں دے دیا ہے حقیقی و دائمی مالک تو وہ خود ہے، زمیندار خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اس کی حیثیت ایک امانتدار کی سی ہے۔ اس لئے اﷲکریم نے زمین کو کسب معاش کے طور پر اختیار کرنے میں جو بنیادی تعلیم دی ہے وہ ہے ”عدل و احسان” اس اصول کی وضاحت ہمیں ان نظائر حدیث رسول ؐسے ملتی ہے جن میں آپ ؐ نے مزارعت کے جواز اور عدم جواز کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔
”رافع بن خدیج رضی اﷲ عنہ سے روایت ہے کہ ظہیر نے بیان کیا کہ آپ ؐنے ہمیں اس چیز ٍے منع فرمایا جو ہمارے لیے فائدہ کاباعث تھی۔ میں نے کہا جو کچھ آپ ؐ نے منع فرمایا حق ہے۔ ظہیر نے کہا مجھے آپ ؐ نے بلاکر فرمایا تم کھیتوں کا کیا کرتے ہو۔ میں نے عرض کا ہم چوتھائی چند وسق کھجور اور جو پر کرایہ پر دے دیتے ہیں۔ آپ ؐ نے فرماا ایسا نہ کرو۔
ازرعوہا او ازراعوہا او امسکوہا قال رافع سمعاً وطاعہ۔
بلکہ یا خود کاشت کرو۔ یا کاشت کے لیے دے دو یارو کے رکھو۔
عن جابر بن عبد اﷲرضی اللہ عنہ قال قال رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم من کانت لہ ارض فلیزرعہا فان لم یزرعہا فلیزرعہا اخاہ۔
فرمایا جس شخص کے پاس زمین ہو اسے چاہیے کہ خود کاشت کرے اگر خود کاشت نہیں کرتا تو اپنے بھائی کو دے دینی چاہیے۔
عن جابر بن عبد اﷲ قال نہی رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم ان یوخذ لا ارض اجرو ”اوحظ”
حضور صلی اﷲ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ زمین کے ذریعہ سے عوض یا اجارہ کا فائدہ اٹھایا جائے۔
جواز مزارعت کے بارے میں آپ ؐ کے احکامات بھی بہت واضح ہیں۔ فرماتے ہیں:
دعن ابن عمررضی اللہ عنہ ان رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم عامل اہل خیبر بشطر مایخرج منہامن ثمر اوزرع۔
”ابن عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اﷲ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو پیداوار میں سے نصف کی ادائیگی پر کاشت کرنے کی اجازت دے دی۔
عن معاذ بن جبل اکری الارض علی عہد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان علی الثلث والربع فہو یعمل بہ الیٰ یوم ہذا۔”
”معاذ بن جبلرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اﷲ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اﷲ علیہم کے عہد سے آج تک زمین تہائی یا چوتھائی پر بٹائی پر دی جاتی ہے۔”
عن سعد بن ابی وقاص المزارع فی زمن النبی صلی اﷲ علیہ ولم کانوا یکرون مزارعہم۔”
” سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ نبوت میں لوگ اپنی زمینیں کرایہ پر دیا کرتے تھے۔”
مذکورہ بالا احادیث میں بظاہر تضاد نظر آتاہے مگر حقیقت یہ ہے جواز اور عدم جواز دونوںمیں عدل و احسان کی بالا دستی قائم کرنا مقصود ہے جیسا کہ کبار صحابہ کرامرضی اللہ عنہ کے بعض روایات و آراء سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے۔
” عبد اﷲ بن عباس رضی اﷲ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اﷲ علیہ وسلم نے زمین کو اجارہ پر دینے کو (مطلقاً) ممنوع قرار نہیں دیا بلکہ یہ پسند فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کو حسن سلوک کے طور پر بغیر معاوضہ دے دی جاے۔”
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے مزارعت کو حرام نہیں کیا مگر یہ ترغیب دی کہ باہم حسن سلوک اور رفق کا معاملہ کریں، لین دین کا معاملہ اس بارہ میں نہ کریں۔
دورِ حاضر میں جو لوگ سینکڑوں مربع اراضی کے مالک ہیں اور زمین کوخود کاشت کرنے یا بٹائی پر دینے کی بجائے، بعض خاندانوں سے نسلاً در نسلاً اپنی زمینوں پر غلاموں کی حیثیت سے کام کروا رہے ہیں اور ان خاندانوں کے سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا یہ رویہ اسلام کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا، کتاب الخراج اور کتاب الاموال میں عمر رضی اﷲ عنہ کے بہت سے آثار ملتے ہیں کہ آپ ؐ نے غلام مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر تقسیم زمین سے متعلق بعض خصوصی اصلاحات جاری فرمائیں۔
علاوہ ازیں اﷲ کی زمین سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اﷲ کے حکم پر خمس وعشور کی ادائیگی بھی کسب معاش کے اسلامی اصولوں میں شامل ہے۔
عہد نبوی میں تجارت:
عرب ایک بے آب و گیاہ ملک ہے جس کا بہت تھوڑا رقبہ کاشت کے قابل ہے اس پر بھی کم ہی توجہ دی جاتی تھی۔ کیونکہ شرفائے عرب زراعت کو کوئی معزز پیشہ تصور نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ہاتھ سے کام کرنے یا دست کاری کے کام کو بھی باعث عار سمجھتے تھے۔ عرب میں عام لوگوں کا پیشہ تو بھیڑ بکریاں، گائے اور اونٹ پالنا تھا لیکن شرفائے عرب کا محبوب مشغلہ تجارت ہی تھا۔ البتہ یمن میں اون کاتنے اور چادریں اور کمبل بننے کا کام بھی ہوتا تھا۔ عربوں کو چونکہ فنونِ سپہ گری سے گہری دلچسپی تھی۔ لہٰذا کہیں کہیں آلاتِ جنگ بھی تیار کئے جاتے تھے۔
نتیجتاً اہل عرب کو اشیاـئے خورد و نوش اور دیگر ضروریات کا سامان باہر سے برآمد کرنا پڑتا تھا۔ بلاشبہ ان دنوں لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کا دور دورہ تھا اور کسی اکے دکے مسافر کا جان و مال محفوظ نہ تھا۔ مگر یہ تجارت عموماً قافلوں کی شکل میں ہوا کرتی تھی۔ قریش مکہ کا تو پاسبان حرم ہونے کی وجہ سے بھی احترام کیا جاتا۔ دوسرے قافلے یا تو قریش مکہ کے اثر سے فائدہ اٹھاتے یا اپنی حفاظت کا سامان خورد ساتھ لے کر چلتے تھے۔ غیر ملکی قافلوں کو بحفاظت گزارنے کے عوض ان سے ٹیکس بھی لیا جاتا تھا۔ ارشاد باری ہے:
لِاِیلف قریش الفہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ہذا البیت الذی اطعمہم من جوع و اٰمنہم من خوف (سورۃ قریش)
”قریش کو مانوس رکھنے کی وجہ سے کہ وہ سردی میں اور گرمی میں سفر سے مانوس تھے، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے پروردگار کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔
ہوتا یہ تھا کہ مکہ میں ہر طبقہ کے لوگ اپنےفروخت کاسامان اس قافلہ کے حوالہ کرتے، جسے وہ اچھے داموں بیچ کر ادھر سے سامان خرید لاتے تھے اس طرح دوہری تجارت سے انہیں دگنا منافع حاصل ہوتا جو بسا اوقات ٥٠% تک پہنچ جاتا تھا۔ اہل مکہ کی خوشحالی کا دارومدار اس قافلے کی کامیابی پر منحصر ہوتا تھا۔ رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی بعثت سے پہلے مدینہ، بصرہ اور شام کے متعدد تجارتی سفر کیے تھے۔
یہ قافلے کتنے بڑے ہوتے تھے، اسکا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ابو سفیان کا وہ قافلہئ تجارت، جو جنگ بدر کا پیش خیمہ ثابت ہوا، دوہزار بار بردار اونٹوں پر مشتمل تھا۔ کئی مؤرخوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ در آمد کی کل تجارت ٥٠ لاکھ دینار سالانہ تک ہوتی تھی۔
پھر یہ تجارتی قافلے قریش مکہ تک ہی محدود نہ تھے۔ یمنی تاجر مکہ اور مدینہ کے راستے شام تک جاتے تھے۔ مدینہ کے یہودی، جوایک سرمایہ دار قوم تھی، شام سے گندم اور شراب در آمد کرتے تھے۔ علاوہ ازیں غیر ملکی تاجروں کی آمد و رفت بھی رہتی تھی۔ ملک میں کئی جگہ بازار اور منڈیاں لگتیں۔ جہاں لوگ خرید و فروخت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ سوداگروں کے قافلے ایران اور عراق سے تجارتی سامان لے کر آتے اور یہاں کی اشیاء اپنے ممالک میں لے جاتے۔ اس طرح یمن سے بحرِ ہند کے راستے ہندوستان سے عراق کے راستے مشرقی ممالک سے اور شام و مصر کے راستے سے افریقہ سے تجارت ہوتی تھی۔ گویا عرب مشرق و مغرب میں بین الاقوامی منڈی بن گیا تھا۔ جس میں شہر مکہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ حج کے دنوں میں تین مشہور تجارتی میلے لگتے تھے عکاظ، مجنہ اور زوالمجاز جو ہمارے دعوی کا زندہ ثبوت ہے۔
(بخاری۔ کتاب التفسیر۔ باب قولہ لیس علیکم جناح)
پھر احادیث میں تجارت کی جن اقسام کا ذکر ملتا ہے اور جن میں سے یبشتر آج بھی رائج ہیں۔ ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ان ایام میں عرب میں تجارت کا کاروبار عروج پر تھا اور تجارت کے سلسلہ میں جو ہدایات احکام مسلمانوں کو دیے گئے ہیں وہ آج بھی مشعل راہ کا کام دیتے ہیں۔ اور تاریخ سے بھی یہ ثابت ہے کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تجارت ہی کی وجہ سے اس دور میں لکھ پتی بن گئے تھے۔
مضاربت:
مضاربت ایک قسم کی تجارتی شرکت ہے جس میں ایک جانب سے سرمایہ اور دوسری جانب سے محنت ہو اس معاہدے کے تحت کہ اسے کاروبار کے نفع میں ایک متعین نسبت سے حصہ ملے گا نیز سرمایہ فراہم کرنے والے اور محنت کرنے والے متعدد افراد ہوسکتے ہیں۔
اصطلاح شریعت میں مضاربت اس عقد کو کہتے ہیں جس میں ایک جانب سے مال ہو اور دوسرے کی جانب سے عمل ہو اور نفع میں دونوں شریک ہوں۔
جس کی جانب سے مال ہو اس کو رب المال کہتے ہیں اور جس کی جانب سے عمل ہو اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ اور جو مال دیا جائے اس کومال مضاربت کہتے ہیں۔
آپ صلی اﷲ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی لوگوں کے ہاں مضاربت جاری رہی در اصل یہ معاملہ عہد جاہلیت میں جانا پہچانا تھا۔ اس وقت قراض کے نام سے موسوم تھا۔ قریش چونکہ تجارت پیشہ تھے اور ان کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ وہ اپنا مال مضاربت پر ان لوگوں کودے دیا کرتے تھے جو منافع میں ایک مقررہ حصہ پر تجارت کرتے تھے۔ تو رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسلام میں جاری رکھا اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
آپ صلی اﷲ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبری رضی اﷲ عنہا کا مال بھی قراض کی صورت میں لے کر بیرون ملک تشریف لے گئے تھے۔
علامہ ابن قیم لکھتے ہیں:
نبی کریم صلی اﷲ علیہ وسلم خرید و فروخت فرمایا کرتے تھے آپ کی خرید و فروخت اکثر ہوا کرتی تھی۔ آپ ؐ بطور آجر اور بطور مستاجر رہے۔ مضاربت اور شراکت میں حصہ لیا وکیل اور توکیل کے فرائض بھی سر انجام دیئے۔
عمررضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادے عبد اﷲ اور عبید اﷲ ایک لشکر میں عراق کی جانب گئے۔ واپسی میں ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے تو انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کے بعد کچھ مال ان کے حوالے کیا اور فرمایا کہ عراق جاکر اس مال سے کچھ سامان اور چیزیں خرید لینا اور اس کے بعد مدینہ جاکرفروخت کردینا اور اصل مال امیر المومنین کے حوالہ کردینا۔ منافع تم رکھ لنیا۔ چنانچہ جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے سامان فروخت کرنے کے بعد منافع اپنے پاس رکھ لیے اور راس المال عمررضی اللہ عنہ کے حوالہ کرنا چاہا عمررضی اللہ عنہ کو اس تمام معاملہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے ان دونوں سے دریافت کیا کہ تمام لشکر کو تمہاری طرح مال دیا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یا امیر المومنین۔ عمررضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم امیر المومنین کے بیٹے تھے اس لیے تمہیں مال دیا گیا۔ آپ نے تمام مال اور اس کے منافع ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو عبد اﷲ نے تو تعمیل کی لیکن عبید اﷲ نے عرض کیا امیر المومنین ایسا کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر مال ہلاک ہوجاتا یا اس میں کوئی نقص پڑ جاتا تو ہم اس کے ضامن تھے۔ عمررضی اللہ عنہ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تو عبد اﷲ خاموش ہی رہے لیکن عبیداﷲ اپنا موقف دہراتے رہے۔ عمررضی اللہ عنہ کے ایک شریک مجلس نے کہا کہ آپ اسے مضاربت اور قراض کی صورت کیوں نہیں دے لیتے۔ تو آپ نے اس پر آمادگی ظاہر کی جس کے نتیجہ میں عمررضی اللہ عنہ نے اصل سرمایہ کے علاوہ آدھا نفع و صول کرنے کے بعد بقیہ نفع عبد اﷲ و عبید اﷲ کے حوالے کردیا۔
مبادلہ کی وہ صورتیں جن میں ذخیرہ اندوزی و اجارہ داری وغیرہ قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں:
اب ہم چند ایسی تجارتی اور لین دین کی شکلوں کو بیان کر رہے ہیں جن کو آپ ؐ نے ممنوع قرار دیا ہے۔
کچھ لوگ شہر سے کئی میل کے فاصلہ پر تجارتی قافلہ سے ملاقات کرتے اور اس سے سستے دام مال خرید کر شہر میں مہنگے دام فروخت کرتے تھے اس کو ”تلقی جلب” کہتے ہیں۔
چنانچہ رسول صلی اﷲ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
لاتلقوا الرکبان لبیع۔
”خریداری کرنے کے لئے قافلوں سے نہ ملاقات کرو۔
دوسری جگہ ہے۔
غلہ لانے والے تاجروں سے نہ ملاقات کرو۔ اگر کسی نے (شہر آنے سے پہلے) ان سے مل کر غلہ خرید لیا اور شہر آنے کے بعد بازار کے بھاؤ کا پتہ چلا تو مہنگا ہونے کی صورت میں ان کو اختیار ہے چاہے تو معاملہ باقی رکھیں اور چاہے تو فسخ کردیں۔
(٢) کچھ لوگ گویا بازار کی سول ایجنسی لے لیتے یعنی تاجروں کے ایجنٹ (دلال) بن کر یہ طے کرلیتے کہ بازار میں باہر سے جو مال آئے گا وہ انہیں کے توسط سے فروخت ہوگا اس کو ”بیع الحاضر لباد” کہتے ہیں۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے فرمایا:
لا یبیع حاضر لباد۔
شہر (بازار) کا آدمی دیہات (باہر) کے تاجر سے بیع کا معاملہ نہ کرے۔
دوسری جگہ ہے۔
لا یبیع حاضر لباد دعوا لناس یرزق اﷲ بعضہم ببعض۔
شہر (بازار) کا آدمی دیہات (باہر) کے تاجر سے بیع کا معاملہ نہ کرے لوگوں کوچھوڑو۔ اﷲ بعض کو بعض کے ذریعہ روزی پہنچاتا ہے۔
طاؤس(راوی) یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اﷲ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مذکورہ حدیث کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا:
لایکون لہ سمساراً۔
شہر کا آدمی دیہات کے تاجر کا دلال نہ بنے۔
”بیع حاضر لباد” کی تعبیر دو طرح منقول ہے۔
(١) پہلی یہ کہ بازار کا آدمی باہر کے تاجر سے (بحیثیت دلال) کہے کہ تم اپنا مال آج کے بھاؤ نہ فروخت کرو بلکہ میرے پاس رہنے دو تاکہ میں اس کو بھاؤ چڑھتے پر گراں قیمت پر فروخت کروں۔
(٢) دوسری یہ کہ بازار کا آدمی ضرورت کے باوجود اہل شہر کے ہاتھ غلہ نہ فروخت کرے بلکہ سادہ لوح دیہاتیوں کے ہاتھ گراں قیمت فروخت کرے۔
(٣) کچھ لوگ تجارتی قافلوں اور غلہ کے تاجروں سے رسد کا ذخیرہ خرید لیتے۔ اور ضرورت کے باوجود روک کر جب اور جس دام چاہتے فروخت کرتے تھے اس کو ”احتکار” کہتے ہیں۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے فرمایا:
من احتکر فہو خاطی۔
جس نے احتکار کیا وہ گنہگار ہے۔
دوسری روایت میں ہے۔
نہی رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ ولسم ان یحتکر الطعام۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے غلہ میں احتکار کرنے سے منع فرمایا۔
ایک اور روایت میں ہے۔
المحتکر ملعون۔
احتکار کرنے والا ملعون ہے۔
یہ ممانعت صرف غلہ کے لئے خاص نہیں بلکہ حالات کی رعایت سے تمام ان چیزوں کو شامل ہے جن کے احتکار سے عام لوگوں کو تکلیف ہو۔
ان صورتوں میں چونکہ اجارہ داری، ذخیرہ اندوزی، طلب و رسد کے قدرتی تناسب میں خلل اندازی اور ناجائز استحصال وغیرہ قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں اس بنا پر ان سے منع کیا گیا ہے۔
خرید و فروخت کی چند اور ممنوع شکلیں:
(١) کچھ لوگ دودھ دینے والے جانور کے تھنوں میں کئی وقت کا دودھ روک لیتے تاکہ تھنوں میں زیادہ دودھ دیکھ کر خریدار زیادہ قیمت لگائے۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے فرمایا:
”اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ نہ روکو۔
دوسری حدیث میں ہے:
”جس شخص نے وہ بکری خریدی جس کے تھن میں دودھ جمع کیا گیا تھا اس کو تین دن تک معاملہ باقی رکھنے اور فسخ کرنے کا اختیار ہے۔
(٢) کچھ لوگ بھیگے ہوئے غلہ کو نیچے چھپا دیتے اور خشک غلہ کو اوپر کرکے کل کو خشک کے دام میں فروخت کرتے تھے۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم ، غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس تشریف لے گئے جب آپ نے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس میں تری محسوس کی غلہ والے سے پوچھا یہ تری کیسی ہے اس نے جواب دیا یا رسول اﷲ بارش سے بھیگ گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں رکھا۔ یاد رکھو جس شخص نے فریب کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔
اس قسم کی صورتوں میں چونکہ دھوکہ، فریب، جہالت اور مستقبل کی سودا بازی وغیرہ جیسی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اس بنا پر ان سے منع کر دیا گیا ہے۔
ایک روایت میں عمومی حیثیت سے دھوکہ و فریب کی تمام شکلوں سے منع فرمایا:
نہی رسول اﷲ صلی اﷲ علہی وسلم عن بیع الغرر۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے دھوکہ کی بیع سے منع فرمایا ہے۔
چند وہ صورتیں جن میں قمار اور احتمال سود کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔
(١) دو معاملہ کرنے والے بغیر حقیقت معلوم کئے ایک دوسرے کے جس کپڑے یا سامان کو چھو دیتے اس کی بیع ہوجاتی تھی، اس کو ”ملامسہ” کہتے ہیں۔
(٢) دومعاملہ کرنے والے ایک دوسرے کی جانب جس کپڑے یا سامان کو پھینک دیتے اس کی بیع ہوجاتی تھی، اس کومنابذہ کہتے ہیں۔
(٣) خریدار بیچنے والے کے جس کپڑے یا سامان پر کنکری رکھ دیتا اس کی بیع ہوجاتی تھی اس کو ”بیع الحصاۃ” یا ”القاء الحجر” کہتے ہیں۔
(٤) درخت پر لگے ہوئے ترپھلوں کو اندازے سے ٹوٹے ہوئے خشک پھلوں کے عوض بیچا جاتا تھا اس کو ”مزابنہ”کہتے ہیں۔
(٥) کھڑی کھیتی( فصل) کو اندازہ سے کٹے ہوئے غلہ کے عوض فروخت کیا جاتا تھا اس کو ”محاقلہ” کہتے ہیں۔
ان صورتوں میں چونکہ قمار (جوا) اور سود کا احتمال پایا جاتا ہے، اس بناء پر ان سے منع کیا گیا یعنی پہلی تین صورتوں میں ایک فریق نفع کی خاطر غیر ضروری خطرات مول لیتا اور بقیہ دو میں ایک جنس کااندازہ اسی جنس سے کمی بیشی کا احتمال پیدا کرتا ہے بالخصوص جبکہ تر کا اندر خشک کے ساتھ ہو اور درخت پر لگے ہوئے کا اندازہ کٹے ہوئے کے ساتھ۔
ان صورتوں کی ممانعت سے متعلق حدیثیں:
چنانچہ ان صورتوں کی ممانعت کے بارے میں حدیثیں یہ ہیں۔
نہی عن الملامسۃ والمنابذۃ فی البیع۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے بیع میں ”ملامسہ” اور منابذہ” سے منع فرمایا۔
نہی عن بیع الحصاۃ۔
رسول اﷲ نے کنکری پھینکنے کی بیع سے منع فرمایا۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نہی عن المزابنۃ والمحاقلۃ۔
بیشک رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے مزابنۃ اور محاقلہ سے منع فرمایا۔
چند وہ صورتیں جن میں ضرر، دھوکہ جہالت وغیرہ کی خرابیاں پائی جاتی ہیں:
(١) باغ کے پھل اور کھیت کی فصل کو تیار ہونے اور پکنے سے پہلے بیچ دیا جاتا تھا۔
چنانچہ رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے فرمایا:
لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔
اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصانا پہنچانا ہے۔
نہی عن بیع النخل حتی یزہو وعن بیع السنبل حتی یبیض ویأ من العاہۃ۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے کھجور کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ پک جائے اور بالی کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ سفید ہوجائے اور آفت کا خطرہ نہ رہے۔
بیع ہونے کے بعد پھل اور فصل برباد ہونے کی صورت میں عمر بن عبد العزیز سے خریدار کو نقصان کا معاوضہ دلانا بھی ثابت ہے۔چنانچہ رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے فرمایا:
لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔
اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصانا پہنچانا ہے۔
نہی عن بیع النخل حتی یزہو وعن بیع السنبل حتی یبیض ویأ من العاہۃ۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے کھجور کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ پک جائے اور بالی کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ سفید ہوجائے اور آفت کا خطرہ نہ رہے۔
بیع ہونے کے بعد پھل اور فصل برباد ہونے کی صورت میں عمر بن عبد العزیز سے خریدار کو نقصان کا معاوضہ دلانا بھی ثابت ہے۔
(٢) خریدی ہوئی چیز کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کیا جاتا تھا۔
آپ ؐ کا ارشاد ہے۔
من ابتاع طعاماً فلا یبیعہ حتی یستوفیہ۔
جس شخص نے غلہ خریدا وہ اس وقت تک نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کرے۔
قبضہ عملا یا قانوناً دونوں میں سے کوئی کافی ہے۔
(٣)( بیع کے ایک معاملہ میں دومعاملے کئے جاتے تھے۔ چنانچہ بیچنے والا کہتا تھا کہ میں نے اس چیز کو نقد دس روپیہ میں بیچا اور ادھار بیس روپیہ کے عوض فروخت کیا یا میں نے اپنا باغ ایک ہزار میں اس شرط پر فروخت کیا کہ تم اپنا مکان سو روپیہ کے عوض فروخت کرو۔
آپ ؐ کا ارشاد ہے۔
نہی رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم عن بیعتین فی صفقۃ واحدۃ۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے ایک معاملہ میں دو بیع سے منع فرمایا۔
(٤) بیع کے درمیان ایسی شرطوں کا اضافہ کیا جاتا جن کا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہ ہوتا تھا۔ مثلاً خریدار کہتا کہ میں کپڑا اس شرط پر خریدتا ہوں کہ تم (بیچنے والا) اس کو کٹادو یا کٹا کر سلادو۔
آپ ؐ کا ارشاد ہے۔
ولا شرطان فی بیع۔
بیع میں دو شرط حلال نہیں ہیں۔
ایک شرط کا بھی یہی حال ہے، دو کی قید واقعی ہے احترازی نہیں ہے۔
ان صورتوں میں چونکہ ایک فریق کو نقصان کا اندیشہ، دھوکہ دہی قیمت میں تفاوت اور ایسی شرطوں کا اضافہ پایا جاتا ہے جن کا معاملہ بیع سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بناء پر ان سے منع کیا گیا۔
چند وہ صورتیں جن میں جہالت، منازعت اور ناجائز استحصال وغیرہ کی خرابیاں پائی جاتی ہیں:
(١) ادھار کی بیع ادھار کے بدلے کی جاتی تھی یعنی ایک شخص کوئی چیز ادھار خریدتا اور مدت معینہ پر وہ قیمت نہ ادا کرسکتا تو دوبارہ اسی چیز کو ادھار خرید لیتا تھا۔ اس کو بیع الکالی بالکالی” یا بیع النسیہ بالنسیہ” کہتے ہیں۔ اس صورت میں دونوں طرف صرف باتیں ہی باتیں ہوتی تھیں، بیع و ثمن دونوں نہ ہوتے تھے۔
چنانچہ رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم کی حدیث ہے:
نہی رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم الکالی بالکالی۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے ادھار کے بدلہ ادھار کی بیع سے منع فرمایا۔
(٢) جو چیز پاس نہ ہوتی اس کی بیع ہوتی تھی پھر وہ چیز بازار سے خرید کر خریدنے والے کے حوالہ کی جاتی تھی۔
حدیث رسول ہے:
نہانی رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس عندی۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں وہ چیز بیچوں جو میرے پاس نہ ہو۔
ابو داؤد و نسائی کی روایت میں ہے۔
قال قلت یا رسول اﷲ یأتینی الرجل فیرید منی البیع ولیس عندی فابتاع لہ من السوق قال لا تبع مالیس عندک۔
حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ مجھ سے بیع کرنا چاہتا ہے حالانکہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن بیع کے بعد میں اس کے لئے بازار سے خرید کر لاتا ہوں، آپ نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کی بیع مت کرو۔
(٣) ایک شخص کوئی چیز خریدتا اور بیچنے والے کو کچھ رقم اس شرط پر ادا کرتا کہ اگر بیع مکمل ہوگئی تو یہ رقم قیمت میں شمار ہوگی اور اگر مکمل نہ ہوئی تو یہ رقم بیچنے والے کی ہوجائے گی۔ اس کو ”بیع عربان” کہتے ہیں۔
حدیث رسول ہے:
نہی رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ ولسم عن بیع عربان۔
رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم نے بیع عربان سے منع فرمایا ہے۔
ان صورتوں میں چونکہ جہالت، منازعت اور ناجائز استحصال وغیرہ قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں اس بناء پر ان سے منع کیا گیا۔
یک جائی طور پر مذکورہ صورتوں کی ممانعت کے وجوہ:
مبادلہ کی مذکورہ شکلوں کوجن وجوہات کی بنا پر منع کیاگیا ہے یکجائی طور پر ان کی فہرست یہ ہے۔
خود غرضی، اجتماعی مفاد کی قربانی، اجارہ داری، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی، اخلاقی اصول کی پائمالی،طلب و رسد کے قدرتی تناسب میں خلل اندازی، مستقبل کی سودا بازی، جہالت، نازعت،ناجائز استحصال، احتمالِ سود، باہمی تعاون کا فقدان اور غلط تشہیر و پروپیگنڈہ۔
یہ وجودہ قدیم و جدیدشکلوں میں پائے جائیں گے ان کی ممانعت ہوگی:
یہ وجوہات مبادلہ کی قدیم و جدید جن شکلوں میں پائے جائیںگے اسلام میں ان کی ممانعت ہوگی اگرچہ ان میں کچھ مادی فائدہ بھی ہو۔ جیسا کہ قرآن حکیم کی درج ذیل آیت میں نفع کے بالمقابل ضرر کے بجائے لفظ ”اثم” کے استعمال سے واضح ہوتا ہے۔
یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہا اکبر من نفعہما۔
وہ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔
کلام عرب میں لفظ ”اثم” کا استعمال اخلاقی و روحانی مفاسدکے لئے ہوتا ہے جبکہ ”ضرر” مادی و جسمانی مضرات کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔
اﷲ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لین دین کے تمام معاملات کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)